فقہی تحقیقی مقالہ ۔۔۔تعارف و طریقہ کار
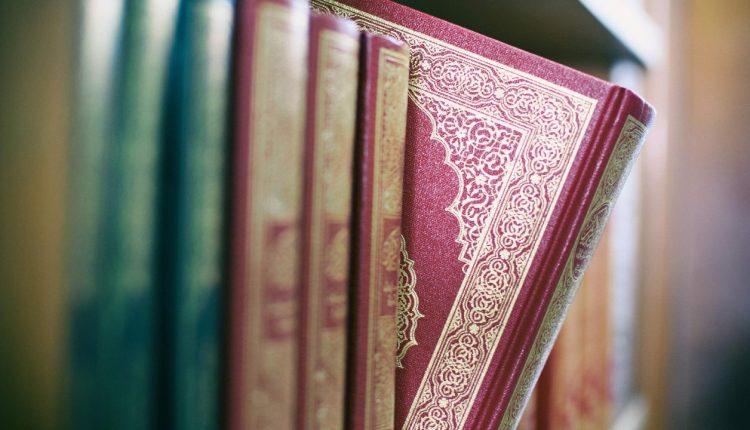
محمد تبریز عالم حلیمی قاسمی
خادم تدریس: دارالعلوم حیدرآباد
مقالہ کے لغوی معنی بات یا گفتگو کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار کو مقالہ کہا جاتا ہے۔ بقول بعض:کسی خاص موضوع پر ٹھوس معلومات کو یکجا کرکے لکھنا ۔ جس پر یا تو پہلے کسی نے کچھ نہ لکھا ہو ۔ یا اگر لکھا ہوتو کم لکھا ہو ۔ یا اس پر مزید لکھا جا سکتا ہو۔ یا اس پر لکھا تو ہو مگر مختلف جگہوں پر، مقالہ کہلاتا ہے ۔اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں: کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہارِ خیال کو مقالہ کہیں گے۔
مقالے تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان بھی تنقیدی اور تحقیقی ہوتی ہے۔
مقالے میں سنجیدہ اور عالمانہ بحث ہوتی ہے۔ یہ عام قارئین کے لیے نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے ۔
مقالہ میں کسی بات کے ثبوت کے لیے باقاعدہ حوالے دیے جاتے ہیں اوران پرمدلل بحث کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔
مقالہ اور مضمون میں فرق:
کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار ’’مضمون‘‘ کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جاسکتا ہے۔
مضمون اور مقالہ درحقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ کہ مضمون قدرے مختصر ہوتا ہے۔ اس کا انداز تاثراتی اور مفہوم سادہ ہوتا ہے، جب کہ مقالہ نسبتاً طویل اور عالمانہ ہوتا ہے۔ مقالہ میں مضمون کی نسبت زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور وہ زیادہ ٹھوس ہوتا ہے۔
تحقیقی مقالہ کیا ہوتا ہے ؟
کسی ایسے موضوع پر مقالہ لکھنا جس پر اس سے پہلے کسی نے کچھ نہ لکھا ہو۔ یا لکھا تو ہو مگر تسلی بخش نہ ہو۔ یا اس پر مزید لکھا جا سکتا ہو۔ اس کے لئے اپنی نئی تلاش و جستجو کے ذریعہ مواد اکٹھا کیا جاتا ہے۔
تحقیق کی حقیقت:
تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کی اصلیت و حقیقت معلوم کرنے کے لیے چھان بین اور تفتیش کرنا۔ اصطلاحا تحقیق کا مطلب ہے کسی منتخب موضوع کے متعلق چھان بین کر کے کھرے کھوٹے اور اصلی و نقلی مواد میں امتیاز کرنا، پھر تحقیقی قواعد و ضوابط کے مطابق اسے استعمال کرنا اور نتائج اخذ کرنا۔‘‘
اسلام میں تحقیق کا معیار:
تحقیق کا مادہ حق ہے، حق اللہ تعالی کی صفت اور اسماء حسنیٰ میں سے ہے جس کے معنی ہیں :ثابت، لازوال۔جو باتیں اورجو چیزیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف (صراحتاً ،دلالتاً،اشارتاً، اقتضاءً یا قیاساً)کسی طرح مستند اور معتبر طریقے سے منسوب ہوں وہ سب حق کہلاتی ہیں۔اس کا دائرہ اگر وسیع کیا جاے تو حق، موافق واقعہ بات کو کہیں گے یعنی سچ بات کو حق کہا جاے گا چاہے وہ دین سے متعلق ہو یا پھر دنیا سے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تحقیق حق تک رسائی کی کوشش کرنے کا نام ہے۔سچ اور حق بات کی تلاش اور اس کی جستجو کا نام حق ہوگا، حق بات تک رسائی میں دلائل کی فراہمی سب سے اہم کام ہے۔اسی لیے فقہی مقالوں میں بنیادی مآخذ سے اراء کو مدلل کرنا بہت ضروری ہے۔
مقالہ کیسے تیار کیا جاے؟
علمی اور تحقیقی کاموں کے لیے اصل میں دو دو چار کی طرح کچھ قواعد اور اصول متعین نہیں ہین؛بلکہ زیادہ تر تجربہ،ذوق،ماحول اور مسلسل اشتغال کے ذریعہ انسان کے اندر کسی موضوع پر قلم اٹھانے اور تحقیق پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے؛اسی لیے کہا جاتا کہ آج ہر آدمی اپنی تحقیق کا واضع بنا ہوا ہے۔تاہم بعض علماء نے اپنے تجربات اور مطالعہ کی روشنی میں تحقیقی مقالے کے کچھ رہنما خطوط متعین کیے ہیں ۔مبتدی طلبہ تحقیق کے لیے انھیں توشہ راہ بنا سکتے ہیں۔ان شاء اللہ فایدہ ہوگا۔
ابتدائی نقوش:
تحقیقی مقالہ کا جب کام شروع کیا جاۓ تو اس سے اللہ تعالی کی رضاء پیشِ نظر ہونا ضروری ہے،ہمارے یہاں یہی کام کی روح ہے اور یہی علماء اور دیگر نام نہاد محققین کے علمی و تحقیقی کاموں کے درمیان مابہ الامتیاز ہے۔اس نیت سے علم و تحقیق میں شانِ قبولیت پیدا ہوتی ہے۔اسی کے ساتھ طلبِ نصرت الہی بھی ناگزیر ہے۔
اپنے مقالے کے سلسلے میں عزم و حوصلہ اور شوق و دلچسپی بھی بہت ضروری چیز ہے اس سے مقالہ کی تکمیل میں مدد ملتی ہے ورنہ اس راہ کے بہتیرے مسافر تھک کر نشانِ منزل بھول جاتے ہیں۔
آج علم و تحقیق کے سلسلے میں مختلف نظریات کام کر رہے ہیں جن میں ایک ہے "ادب براے ادب” اور "تحقیق براے تحقیق”۔علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایسے بے مقصد ادب اور تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے؛بلکہ ہمارے یہاں ایسی تحقیق مطلوب ہے جو دین سے مربوط ہو، اس سے کسی دینی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہو یا اس سے انسانیت کا نفع متعلق ہو۔
تحقیقی مقالے میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ قلم افراط و تفریط کا شکار نہ ہو بلکہ عدل اور اعتدال کو پیشِ نظر رکھنا ناگزیر ہے،سنجیدگی،متانت اور ادب و احترام کی حدوں کو پار نہ کیا جاۓ،کسی مسئلہ میں اختلافِ راۓ بری بات نہیں ہے لیکن اختلاف میں طنز و تعریض اور تضحیک و تنقیص نہ درست ہے اور نہ ہی مفید۔
موضوع کا انتخاب:
فقہی مقالے دو طرح کے ہوتے ہیں:کبھی ادارہ یا تنظیم کی طرف سے مختلف مفتیان کرام اور اہل علم کی خدمت میں سوال نامے بھیجے جاتے ہیں جن کے تحقیقی جوابات مقالے کی شکل میں مطلوب ہوتے ہیں،مقالہ کی یہ قسم قدرے آسان ہے کیوں کہ موضوع اور تحقیق کا دائرہ متعین اور محدود ہوتا ہے؛ لیکن چونکہ یہ جدید مسائل سے متعلق ہوتا ہے اس لیے محنت طلب ہوتا ہے۔مقالہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ خود انسان کوئی موضوع طے کرتا ہے یا ماحول اور ضرورت متقاضی ہوتی ہےکہ فلاں موضوع پر کچھ لکھنا چاہیے۔اس کے لیے اہل تحقیق نے کچھ ضروری باتیں لکھی ہیں کہ اگر اپنے مقالے میں ان کی رعایت کی جاۓ تو ایک تحقیقی فقہی مقالہ تیار ہوسکتا ہے اور جس سے علم و تحقیق کے گلستاں میں نئے لال و گُل کھلیں گے۔
موضوع منتخب کرتے وقت پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے ہمیں مناسبت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے والا خود سے سوال کرے کہ کیا وہ موضوع اس قابل ہے کہ اسے اپنی تحقیق اور محنت کا محور بنایا جاۓ؟ اس ذیل میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا موضوع منتخب کیا جاۓ جس کی سماج،معاشرہ یا علمی دنیا میں بہت ضرورت ہو تاکہ اس کا نفع عام اور تام ہوسکے۔اس مرحلہ میں یہ سوچنا بھی ناگزیر ہے کہ کیا اس موضوع پر کوئی نئی چیز تیار ہوسکتی ہے یا کسی نئے اسلوبِ نگارش کے ذریعہ ایسا کام ہوسکتا ہے جو پہلے کاموں سے الگ اور زیادہ مفید ہو۔اس موقع پر یہ بھی غور کیا جاۓ کہ کیا میں اس موضوع کا حق ادا کرسکتا ہوں؟ جس زبان میں متعلقہ مواد ہے اس میں اپنی مہارت کا جائزہ لینا،اوقاتِ فرصت دیکھنا، مطلوبہ موضوع پر مطالعہ کے لیے سفر کی ضرورت پڑتی ہو یا مخطوطات و مطبوعات کے خریدنے یا ان کی فوٹو لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہو تو اس کے لیے مالی وسائل کا اندازہ کر لینا بھی لازم ہے۔
ان سب کے بعد مقالہ نگاری کا ارادہ رکھنے والے طالب علم کو پھرایک دفعہ غور کرنا چاہیے کہ اس موضوع پر اسے شرحِ صدر اور قلبی اطمینان ہے یا وہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہے؛ کیونکہ شرح صدر کے بغیر کسی موضوع پر لکھنا پرانی لکیروں کو زندہ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ان سب باتوں میں جان پیدا کرنے کے لیے مناسب ہے کہ اس سلسلے میں اپنے کسی استاذ یا کسی ماہرِ فن سے مشورہ کرلیا جاۓ اور اس کے مشوروں کی روشنی میں علم و تحقیق کا سفر شروع کیا جاے۔
انتخابِ موضوع میں کتب خانوں کی سیر ،علمی و تحقیقی سیمیناروں میں شرکت اور رسائل وجرائد اور تحقیقی کاموں کے تعارف نامے دیکھنے سے بہت مدد ملتی ہے۔
ذیلی عناوین قائم کرنا :
انتخابِ موضوع کے بعد اہم کام عنوانات کی خاکہ سازی ہے،بات آسانی سے ذہن نشیں ہو جاۓ اور ضرورت مند کی تشنگی بجھ جاۓ اس کے لیے ذیلی عنوانات کی ترتیب و تہذیب کی بڑی اہمیت ہے،اس کی وجہ سے مقالہ وقت پر تیار ہو جاتا ہے،لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں اصول سے زیادہ ذوقی وجدان کا دخل ہے۔تاہم اصولی طور پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے مقالے کا ایسا نام تجویز کیا یا کرایا جاۓ جو مختصر،واضح،جامع اور جاذب قلب و نظر ہو۔
ذیلی عناوین میں پہلے چند مرکزی عنوانات قائم کیے جاتے ہیں،ان میں سب سے پہلے "ابتدائیہ” ہوتا ہے جس میں موضوع کا تعارف،اس کی اہمیت و ضرورت اور اس کی شرعی اور عملی حکمت کا ذکر ہونا چاہیے، ابتدائیہ کو "تعارفِ مسئلہ” یا تعارفِ موضوع” لکھ سکتے ہیں۔علاوہ ازیں مرکزی عنوانات کے ساتھ ذیلی عناوین قائم کرنا ضروری ہوتا ہے،اول الذکر کی حیثیت باب کی ہوتی ہے جبکہ ثانی الذکر مقالہ میں فصل کا درجہ رکھتا ہے،موضوع منتخب کرنے کی خاص وجہ کا تذکرہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔یاد رہے یہ ہدایات اس کے لیے ہیں جو تنہا کوئی مقالہ تیار کررہا ہو،لیکن اگر کہیں کئی لوگ مل کر کسی ماہرِ فن کے زیرِ نگرانی تحقیقی مقالہ تیار کر رہے ہوں تو موضوع کا تعارف اور اس کی اہمیت و ضرورت پر خامہ فرسائی نگراں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
مضمون کے اختتام پر ایک ایسا اختتامیہ لکھا جاتا ہے جس میں پوری بحث کا خلاصہ اور نتیجہ سمٹ کر آجاۓ،اسے "حاصل بحث” یا "خلاصہ بحث” کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ نام کے ساتھ عنوانات مرکزی ہوں یا ذیلی انھیں اتنا واضح اور جامع ہونا چاہیے کہ دیکھ کر نہ صرف یہ کہ مضمون سمجھ میں آجائے بلکہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاۓ۔اس کے لیے اہلِ علم اور اصحابِ فقہ و فتاوی کی فقہی تحقیقات کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے،اس سلسلے میں اردو ادب کی معیاری کتابیں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ مقالہ نگار اپنے ذوق اور قارئین کی ضرورت کے پیش نظر کچھ حذف و اضافہ بھی کرسکتا ہے۔
مواد کی فراہمی:
جس موضوع پر مقالہ لکھا جارہا ہے ضروری ہے کہ اس کے لیے مقالہ نگار مصادر اور مراجع کو متعین کرے،متعلقہ موضوع پر اگر پہلے سے مقالے یا کتابیں لکھی گئی ہیں تو انھیں جمع کرنا،اس کے ساتھ ان کتابوں کی نشاندہی کرنا جو خاص اسی موضوع کے لیے لکھی گئی ہیں اور انھیں مراجع اور مآخذ کا درجہ حاصل ہے،کسی بھی موضوع پر خامہ فرسائی کے لیے بنیادی مآخذ سے واقفیت بہت ضروری ہے،مراجع اصلیہ سے جتنا زیادہ استفادہ ہو اتنا ہی مقالہ کا معیار اونچا ہوگا۔ مآخذ کا علم ماہرینِ فن اور کتب خانوں میں آنے جانے سے ہوتا ہے،نیز جو کتابیں یا مقالے اس موضوع پر لکھے گئے ہیں ان میں جن مراجع سے استفادہ کیا گیا ہے انھیں دیکھنے سے بھی اصل مراجع تک رسائی ہو جاتی ہے۔فقہی مقالے کی ترتیب میں دیگر مسالک کی بنیادی کتب سے واقفیت بھی ضروری ہے یعنی فقہِ حنبلی،فقہ شافعی اور فقہ مالکی کے بنیادی مراجع اور امہات کتب کی جانکاری بھی ضروری ہے بلکہ مقالے کے استناد و اعتبار میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے،مکتبہ شاملہ اور نیٹ کی وجہ سے یہ کام اب بہت مشکل نہیں رہا۔اس کے ساتھ ساتھ ایسے مصادر کو متعین کرنا بھی لازم ہے جن میں متعلقہ بحث ضمنی طور پر ملے گی،لغات اور معاجم کے ساتھ اسرار و حکم اور مقاصد شریعت سے متعلق کتابوں کی فہرست بھی بنا لی جاۓ تاکہ بوقت ضرورت استفادہ کیا جا سکے۔ڈیجیٹل اور آن لائن ذخیرہ بھی محفوظ کر لینا ضروری ہے۔کتابوں کی فراہمی کے بعد ساری کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جاۓ،مقالہ میں گہرائی ، عُمُق اور شانِ تحقیق پیدا کرنے کے لیے اپنے پاس معلومات کا خزانہ ہونا بہت ضروری ہے،ہمارے استاذ مولانا نور عالم خلیل امینیؒ سابق استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے "ایک سطر لکھنے کے لیے دس سطر پڑھنا چاہیے اور ایک صفحہ لکھنے کے لیے دس صفحے پڑھنا چاہیے”اور بقول مولانا سید سلیمان ندویؒ کے: اتنا مطالعہ کرے کہ دماغ کا برتن بھر کر ابلنے لگے،تب لکھنے کی سوچے۔
دورانِ مطالعہ مواد اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیرِ بحث موضوع کو جن ابواب، فصول اور ذیلی عناوین پر آپ نے تقسیم کیا ہےان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اوراق مخصوص کر لیے جائیں اور ان اوراق میں مسائل و دلائل اور اصول و قواعد جمع کرتے چلے جائیں،اگر پوری بحث لکھنا دشوار ہو تو کم از کم صفحہ اور جلد کی وضاحت کے ساتھ اشارہ لکھ لینا چاہیے تاکہ مقالہ تحریر کرتے وقت دوبارہ تلاش نہ کرنا پڑے۔
مقالہ کی ترتیب و تبییض:
ابواب و فصول میں جمع کردہ مواد کی روشنی میں اب مقالہ لکھنے اور مرتب کرنے کے لیے اپنے کو تیار کر لینا چاہیے،ترتیبِ مقالہ کے وقت چند باتیں ملحوظ رکھنا چاہیے:تحریر سہل اور آسان ہو،جملے چھوٹے چھوٹے ہوں،فقہی مقالوں میں تعبیرات اور جملے کے انتخاب میں فقہی مزاج و مذاق کی رعایت کرنی چاہیے، تمہیدی گفتگو پر خصوصی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،مشکل الفاظ اور نامانوس محاورات سے گریز کرنا چاہیے،اس کے لیے ابتداء میں یہ بات ضروری ہے کہ ہر سطر کے بعد دو تین سطر چھوڑ کر مقالہ تحریر کیا جاۓ تاکہ چھوڑے گئے حصے میں حذف و اضافہ کیا جا سکے،اگر ایک مسئلہ مختلف کتابوں میں موجود ہو تو ساری کتابوں کی عبارت نقل کرنے کے بجاۓ ایسی کتاب کا انتخاب کرے جس کی عبارت بہت واضح اور مقصود کو محیط ہو،مبتدی طلبہ کے لیے یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترتیبِ مقالہ سے پہلے چند ایسی کتابوں کا مطالعہ کر لیں جو فقہی مقالات و تحقیقات پر لکھی گئی ہیں: مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہ کی فقہی مقالات،مفتی محمد شفیع صاحب کی جواہر الفقہ،مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جدید فقہی مسائل،مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی نفائس الفقہ اور مفتی رضوان صاحب پاکستان کی کتاب علمی و تحقیقی رسائل وغیرہ اسلوبِ نگارش اور اندازِ تحریر کے حوالہ سے بہت مفید ہیں۔
فقہی مقالوں میں اختلافِ ائمہ کا ذکر ناگزیر ہوتا ہے،اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہید کے بعد پہلی راۓ کا ذیلی عنوان لگا کر قائلین کے نام اور ان کے دلائل انصاف اور علمی دیانت داری کے ساتھ ذکر کیے جائیں پھر دوسری راۓ کا ذیلی عنوان لگا کر اس راۓ کے قائلین اور ان کے دلائل لکھے جائیں،مقالہ نگار جس امام کا مقلد اور جس راۓ کا ہم موقف ہے اس راۓ کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا جاتا ہے،اپنا نقطہ نظر مدلل کرنے کے بعد مخالفین کے دلائل کا علمی جائزہ پیش کرتے ہوۓ جواب لکھنا چاہیے،اس طرز کو سیکھنے کے لیے ہدایہ کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔اگر اپنی دلیل میں کچھ سُقم محسوس ہو تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔دونوں طرح کی بحث کے بعد اگر اپنی کوئی راۓ ہو تو اسے بھی ذکر کیا جاسکتا ہے،مخالفین کے اسماء اور ان کے مسائل و دلائل کے ذکر کے وقت ادب و احترام اور غیر جانب دارانہ اسلوب کو پیشِ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے،اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں اس وضاحت و قوت کے ساتھ لکھیں کہ گویا وہی آپ کی راۓ اور دل کی آواز ہے۔اگر کہیں کسی کتاب کے مصنف کا نام لکھنا پڑے تو نام کے ساتھ اس کی تاریخ وفات بھی لکھ دینا مروج ہے۔
اگر بحث دراز ہو گئی ہو تو خلاصہ بحث کے عنوان سے چند سطروں میں مسائل و دلائل کی جانب اشارہ کردیا جاۓ،تاکہ قاری کما حقہ مستفید ہو سکے۔اگر مقالہ کسی سوال نامے کے پس منظر میں تیار کیا گیا ہے تو خلاصہ کے طور پر ترتیب وار جوابات لکھ دیے جائیں تاکہ آپ کا نقطہ نظر خوب واضح ہو جاۓ۔
اس مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ مقالہ کی تبییض کا ہے یعنی جو مقالہ آپ نے کیف ما اتفق اور رف کے انداز میں تیار کیا تھا جسے مسودہ کہتے ہیں اور جو قابل استفادہ نہیں ہوتا اب اسے قابلِ استفادہ بنانا ضروری ہے چنانچہ مندرجہ ذیل امور کے ذریعہ مسودہ صاف ستھرا کیا جا سکتا ہے:
اے فور سائز یا فل اسکیپ سائز کے کاغذ میں مقالہ اس طرح لکھا جاۓ کہ ہر صفحہ کی دائیں جانب ڈیڑھ انچ اور بائیں جانب ایک انچ اور صفحہ کی بالائی جانب سے سوا انچ اور نیچے کی جانب سےنصف انچ جگہ چھوڑ دی جاۓ،اس سے مقالہ خوبصورت نظر آتا ہے نیز اگر کاغذ کا کنارہ پھٹ گیا یا مڑ گیا تو اس سے اصل عبارت کو نقصان نہیں پہنچتا۔اگر آپ خوشخط ہیں تو سطر چھوڑے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں؛لیکن اگر خط صاف نہ ہو تو ایک سطر چھوڑ کر لکھنا مناسب ہے،مقالہ ہاتھ سے لکھنے کی صورت میں مختلف رنگوں اور خط کی مختلف اقسام کا استعمال ناگزیر ہے،مگر اس میں مبالغہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔اگر مقالہ کمپیوٹر پر لکھا جارہا ہو تو پرنٹ کی سیٹنگ مذکورہ اصول کے مطابق کرلینا چاہیے۔
پیراگراف کی پہلی سطر باقی حصے کے مقابلہ میں دو لفظ کے بقدر چھوڑ کر شروع کرنا چاہیے،سمجھنے کے لیے کسی بھی کتاب کا کوئی پیراگراف دیکھ لینا مناسب ہے۔پیراگراف کے لیے موزوں مقامات کا انتخاب کرنا چاہیے،اور پیرا گراف نہ بہت چھوٹے ہوں اور نہ بہت لمبے۔
مرکزی عناوین سطر کے وسط میں اور ذیلی عناوین سطر کی دائیں جانب لکھنا چاہیے۔
جہاں کہیں اقتباس نقل کرنا ہو تو اس کو حوض میں لکھنا چاہیے،حوض سمجھنے کے لیے کسی کتاب میں موجود اقتباس کو دیکھ لیا جاۓ۔حوض میں بھی پہلی سطر دو لفظوں کے بقدر جگہ چھوڑ کر شروع کرنی چاہیے اور آج کل اقتباس کو واوین میں نقل کرنے کا رجحان بھی ہے اس لیے اسے واوین میں نقل کر سکتے ہیں۔اگر اقتباس پانچ سطروں سے زاید نہ ہو تو اسے مقالہ ہی کے رسم الخط اور حجم میں لکھا جاۓ گا اور بین السطور کا فاصلہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔اگر اقتباس طویل ہو تو دونوں طرف قدرے حاشیہ چھوڑ کر،دوسطروں کے درمیانی فاصلے کو کم کرکے اور اقتباس کے الفاظ کو بقیہ الفاظ سے چھوٹا لکھا جاۓ گا تاکہ دونوں میں واضح فرق نظر آۓ۔اقتباس کا متن نقل کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے،ایک ایک لفظ کو بغیر کسی ترمیم کے نقل کرنا چاہیے،اگر اقتباس میں کچھ غلطی ہو تو اس کی تصحیح نہ کی جاۓ بلکہ اسے جوں کا توں نقل کرکے قوسین میں اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔
مقالہ میں جہاں تک ہو سکے متکلم کی ضمیر (میں/ہم/میرا/ ہمارا) سے پرہیز کیا جاۓ،بلکہ ایسی عبارت سے گریز کیا جاے جس سے اپنی ذات کا اظہار یا تعلی کا تاثر ملے،مقالہ نگار،راقم الحروف اور راقم السطور جیسے الفاظ کا استعمال مناسب ہے۔
حوالہ جات لکھنے کا طریقہ:
ایک دور تھا کہ کتابیں حوالہ جات کے بغیر لکھی جاتی تھیں اور ایک دور یہ آیا کہ حوالہ جات کے بغیر کتاب اور تحریر مستند نہیں سمجھی جاتی ہے،اس لیے اب تحقیقی مقالوں میں حوالہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔حوالہ کا مقصد چونکہ اصل کتاب تک رسائی ہے اس لیے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہونا چاہیے،لکھنے والا خود کوئی طریقہ وضع کرسکتا ہے تاہم یکسانیت قائم رکھنے کے لیے آج کل حوالہ جات لکھنے کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے مصنف کی نسبت،اس کے بعد مصنف کا نام،پھر کتاب کا نام اس کے بعد جلد نمبر پھر صفحہ نمبر اس کے بعد مطبوعہ کا رمز "ط” لکھ کر مطبع کا نام،آخر میں سن اشاعت لکھا جاۓ،(بعض کتابوں پر سنِ اشاعت نہیں ہوتا وہاں سنِ اشاعت کے بعد "درج نہیں” کا جملہ لکھا جاتا ہے۔) مثلا: العینی،بدرالدین،عمدة القاری: ۵/ ۵۵۰ ط: زکریا بک ڈپو دیوبند، سنِ اشاعت: ۲۰۱۰ ۔ حوالہ میں اگر قرآن کی آیت لکھنی ہو تو سورت کے نام کے ساتھ آیت نمبر بھی لکھا جاتا ہے اور حدیث کی صورت میں آج کل کتاب کے نام کے ساتھ صرف حدیث نمبر لکھنے کا رواج ہے البتہ اس صورت میں حدیث کے مرقم نسخے متعدد ہوں تو تحقیق و ترقیم کا کام کرنے والے کی وضاحت بھی ضروری ہے،حدیث کے حوالہ میں رقم حدیث کے ساتھ یا اس کے بغیر صرف کتاب کا نام مع جلد و صفحہ لکھنے کا چلن بھی موجود ہے،علاوہ ازیں بعض محققین حوالوں میں باب اور فصل لکھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں،اس لیے حسب ضرورت اس طرز کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔
نوٹ: اگر کتاب اور مصنف کا نام علمی دنیا میں بہت مشہور ہے تو نام کا اشارہ بھی کافی ہے،بعض دفعہ ایسا بھی کیا جاسکتا ہے کہ شہرت کی وجہ سے مصنف کا ذکر نہ ہو بلکہ صرف کتاب کا نام لکھ دیا جاۓ،البتہ اگر ایک ہی نام کی کئی کتابیں ہوں جیسے الاشباہ والنظائر تو مصنف کے نام کی صراحت ضروری ہے۔پوری کتاب میں اگر ایک ہی ایڈیشن سے استفادہ کیا گیا ہو تو سن طباعت اور مطبع کی صراحت ہر جگہ ضروری نہیں ہے یا تو پہلی جگہ ساری تفصیلات ذکر کردی جائیں یا پھر اخیر میں مراجع کے عنوان کے تحت ہر کتاب کی تفصیل یکجا ذکر کی جاۓ۔
اگر کہیں آن لائن استفادہ کیا گیا ہے تو اس سائٹ کا یا مکتبہ کا حوالہ لکھ دینا چاہیے۔حوالہ جات کے سلسلے میں بعض اہل علم یہ طرز بھی اختیار کرتے ہیں کہ حوالہ کی جگہ صرف ترتیب وار نمبر ڈال کر اخیر میں اسی ترتیب سے ساری تفصیلات درج کرتے ہیں۔
حاشیہ لکھنے کا طریقہ:
حواشی لکھنے کی ضرورت عموما کتابوں میں ہوتی ہے،مقالہ میں اس کی ضرورت کم ہوتی ہے تاہم اگر کوئی اپنے مقالے میں حواشی کا اہتمام کرنا ضروری سمجھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ترتیب سے حاشیہ نمبر لکھتا جاۓ اور اسی ترتیب سے اخیر میں نمبروار حاشیہ لکھ دیا جاۓ،اس سے قاری کو مقالہ پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی،حاشیہ میں شخصیات، مقامات،واقعات،کتابیات اور اصطلاحات پر تعارفی نوٹ لکھا جاتا ہے۔
تکمیلِ مقالہ کے بعد:
جب مقالہ مکمل ہوجائے تو اس پر دوچار مرتبہ اصلاحی نظر ڈال لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہر اعتبار سے مقالہ مستند اور اپنے موضوع پر مکمل ہو،اپنے طور پر مطمئن ہو جانے کے بعد کسی ماہرِ فن کی نظروں سے گذار دینا مقالہ کے اعتبار و استناد کے لیے بہت مفید ہے،یہ کام ابتدائی دور میں بہت ضروری ہے،جب اس میدان میں ایک عرصہ گزر جاۓ تو اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی،آدمی اپنی ذمہ داری پر بھی لکھ سکتا ہے۔
مقالہ کے اجزاء:
آج کل بعض اداروں میں طویل تحقیقی مقالوں کے لیے مندرجہ ذیل اسلوب ضروری سمجھا جاتا ہے۔افادہ کی غرض سے یہاں لکھا جاتا ہے۔
ٹائٹل پیج:
خوبصورت ٹائٹل پیج جس پر مقالہ کا عنوان ، مقالہ نگارکا نام ، رہائش وغیرہ کا اندراج کیا جائے ۔
تعارف مقالہ نگار:
مقالہ نگار مختصر تعارف اپنے مقالہ کی ابتداء میں درج کرے ۔
ماہرِ فن کی رائے:
اپنا مقالہ کسی ماہرِ فن سے پڑھوا کر اس سے مقالہ سے متعلق رائے درج کروائی جائے ۔
پیش لفظ:
مقالہ نگار پیش لفظ درج کرے جس میں اپنے مقالہ کا خلاصہ اور مقالہ لکھتے ہوئے جو کمی بیشی رہ گئی ہو یا مشکل پیش آئی ہو وغیرہ اس کا ذکر مختصر پیرائے میں کردے ۔
فہرست:
اپنے مقالہ کے مرکزی مواد کے عناوین کی فہرست شروع میں درج کرے جس سے قاری کو مقالہ کا مضمون سمجھنے میں آسانی پیدا ہو ۔ اور اگر اس کے پاس وقت نہ بھی ہو تو وہ عناوین کو پڑھ کر اپنی ضرورت کے عنوان کے تحت لکھے ہوئے اقتباس کو پڑھ لے ۔
اصل مواد:
فہرست کے بعد مقالہ نگار اصل مواد کو ہیڈنگ ، سب ہیڈنگ اور ضرورت پر تیسری ہیڈنگ بنا کر انکے تحت تقسیم کرے ۔
مقالہ نگار اس بات کا خیال رکھے کہ جہاں ہیڈنگ شروع ہو رہی ہو وہاں سے پیج کا آغاز ہو رہا ہو ۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پیج ختم ہو رہا ہو۔ اس سے پڑھنے والے پر برا اثر پڑتا ہے ۔
حوالہ جات:
اصل مواد کے تحت جن جن کتب سے حوالہ جات کا اندراج کیا گیا ہے۔ انکا مکمل حوالہ فٹ نوٹ میں درج کرنا ۔
اشاریہ:
اصل مواد کے اختتام پر اشاریہ کا اندراج کیا جاتا ہے جو درج ذیل چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے:
مضامین، شخصیات، مقامات، مراجع اور کتابوں کے نام، ان سب کو حروف تہجی کے اعتبار سے درج کیا جاتا ہےاور مقالہ میں جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہو ان کے صفحات نمبر درج کیے جاتے ہیں۔اس کو سمجھنے کے لئے کسی ایک کتاب مثلا "وہ کوہ کن کی بات”کو دیکھ لینا چاہیے۔
رموز اوقاف:
زبان وتحریر کا مقصد اپنی بات دوسروں تک پہونچانا ہوتا ہے، روزمرہ کی بول چال میں ہم چہرے کے تاثرات، لب و لہجے کے تغیرات، آواز کے زیر و بم اور بات کے دوران موزوں جگہوں پر وقفے دے کر اپنی بات کو زیادہ موثر بناتے ہیں لیکن تحریر میں ہمارا قاری ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ موثر بنانے کے لیے اور جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کے لیے تحریر کے دوران میں کچھ علامتوں اور اشاروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اِن اشاروں اور علامتوں کو ’’رموز اوقاف‘‘ کہتے ہیں۔مقالے فقہی ہوں یا ادبی ان میں بھی رموز اوقاف کی رعایت موجودہ دور میں بہت ضروری ہے۔رموز اوقاف‘‘ یعنی وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، متعدد ہیں۔اس موضوع پر مستقل کتابیں اور مضامیں موجود ہیں۔مبتدی مقالہ نگار طلبہ کو اپنے مقالے میں رموز اوقاف کی رعایت کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔مولانا نور عالم امینی صاحبؒ کی کتاب "حرف شیریں” اس حوالہ سے بہت مفید ہے۔
حرف آخر:
سطور بالا میں تحقیقی مقالے کے سلسلے میں جو اصولی باتیں تحریر کی گئی ہیں،وہ مختصر طور پر پیش کی گئی ہیں،ورنہ مقالہ نویسی کے اصول و قواعد پر مستقل کتابیں بھی موجود ہیں تاہم اسلامی اور فقہی مقالوں میں تحقیقی رنگ پیدا کرنے کے لیے منضبط اصول و قواعد کم ہیں،جن اداروں میں یہ کام ہوتا ہے وہ اپنے طور پر اصولِ تحقیق متعین کر لیتے ہیں اور طلبہ اسی نہج پر کام انجام دیتے ہیں؛البتہ اصول تحقیق کے سلسلے میں عربوں کا مزاج الگ ہے،چنانچہ ان کے یہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے؛اسی وجہ سے ان کے یہاں اس موضوع پر متعدد مفصل کتابیں موجود ہیں۔ذیل میں اس حوالے سے کچھ کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں اور فقہی مقالوں میں تحقیقی معیار پیدا کرنے کے لیے ان کی رعایت کریں۔
البحث العلمی(عربی) ، الدکتور عبد العزیز بن عبد الرحمن،ناشر: مکتبة العبیکان ریاض
اسلامی اصول تحقیق، پروفیسر باقر خان خاکوانی، ناشر: ادبیات اردو بازار لاہور
علمی موضوعات پر مطالعہ و تحقیق کا طریقہ،مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب،ناشر:المعھد العالی الاسلامی حیدرآباد۔
اسلامی علوم میں تحقیق اصول،ترجیحات اور معیار، ڈاکٹر محمد امین،ناشر:مکتبہ البرھان لاہور۔

Comments are closed.